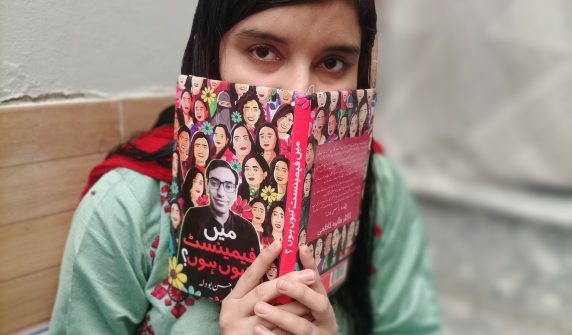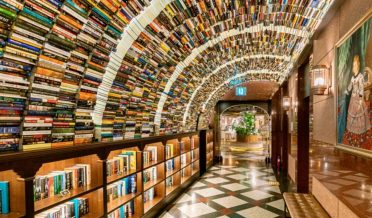علی عبداللہ
قبل از تقسیم اور مابعد تقسیم برصغیر کی سماجی تاریخ کے موضوع پر آگ کا دریا ، اداس نسلیں ، آنگن ، گریز ، راجہ گدھ ، غلام باغ اور کئی چاند تھے سرِ آسماں سمیت دیگر کئی ناول موجود ہیں، لیکن ناول خس و خاشاک زمانے میں مستنصر حسین تارڑ نے جو تکنیک اور اسلوب استعمال کیا ہے وہ شاید باقی ناولوں میں دکھائی نہیں دیتا- اس ناول کے لاتعداد کرداروں سے جو کہانیاں وجود میں آتی ہیں وہ بذات خود چھوٹے چھوٹے افسانوں کی صورت پڑھی جانے کے قابل ہیں- مگر یوں نہیں ہوا کہ کسی مقام پر مصنف کی مختلف کہانیوں پر توجہ دینے میں ان کا آپسی ربط کہیں ٹوٹا ہو- تمام کردار ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے منسلک ہیں اور یوں ناول کسی چناب کی مانند قاری کو روانی سے اپنے ساتھ بہاتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ 740 صفحات کا یہ ناول اپنی تکمیل کو پہنچ کر “دل دریا سمندروں ڈونگے” میں کہیں روپوش ہو کر دل کی لہروں میں طلاطم پیدا کر دیتا ہے- میں سمجھتا ہوں یہ ناول ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھنے کے لائق ہے کہ اس میں صرف ایک موضوع نہیں بلکہ تاریخ،تقسیم ہند، 65 کی جنگ، مشرقی پاکستان کی علیحدگی، نائن الیون و مابعد دنیا کا ایک نیا چہرہ، ناجائز بچے اور ہم جنس پرستی جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے-
مصنف کا ہر موضوع کو کرداروں کے ساتھ اور ہر کردار کو ایک جاندار کہانی کے ساتھ منظر عام پر لانے کا فن واقعی قابل تعریف ہے- مصنف کی قوت مشاہدہ، ماضی کی یادیں، تاریخ و جغرافیے سے واقفیت،پنجاب کی خوبصورت عکاسی اور الفاظ و بیان پر گرفت بلاشبہ اس ناول کو بہترین کتب کی فہرست میں جا رکھتی ہے- بخت جہاں ناول کا سب سے مضبوط کردار ہے تو وہیں سرو سانسی بھی مضبوطی میں کچھ کم نہیں- لیکن دونوں کے مزاج اور شخصیت میں تضاد، بخت جہاں کا نسلی تفاخر اور اکھڑپن جبکہ سروسانسی کا آخر تک مردار خور رہنے کا احساس ناول کو دلچسپ بناتا ہے- بخت جہاں کا کردار ڈارونزم کے حیوانی کردار کے فلسفے کے نتیجے میں آنے والے مغربی نفسیاتی شعور جسے “انسان کی حیوانیت” سے تعبیر کیا جاتا ہے پر پورا اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کی رو سے روحانی احساسات مکمل لغو ہیں اور انسان کا حیوانی خواہشات و جسمانی لذات کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے- دوسری جانب سروسانسی بھی اسی فلسفے کے تحت وجود میں آنے والے دوسرے نفسیاتی شعور “زندگی کی ناقدری،حقارت کا احساس اور وجود کی کسی بھی بلند غایت سے انکار” کا شکار بھی نظر آتا ہے-
پنجابی ثقافت کا بیانیہ اور پنجابی زبان کی ملاوٹ اس ناول کی خاص بات ہے- ’دریک‘ کا درخت جس پر ترکونے اُگتے ہیں اور ’شریں‘ جس کے بارے میاں محمد بخش نے کہا تھا،
“وچھڑ گیاں دی کی اے نشانی، جیویں دیگر رنگ شرینہاں” ایسے ہی استعاروں اور تشبیہات سے مصنف نے ناول کو تازگی اور دلکشی بخشی ہے- ایک جگہ لکھتے ہیں”چناب کے گدلے ٹھنڈے سیت پانیوں پر جن میں سوہنی کے گھڑے کی گھلاوٹ تھی، اس سرگی سویر میں کچی لسی ایسی ہلکی دھند ٹھہری ہوئی تھی جس کے پار یکھا بھی جاسکتا تھا اورنہیں بھی دیکھا جا سکتا تھا- اس دھند کے اندر چڑیاں چہکتی تھیں۔۔۔ غل کرتی تھیں اور کبھی کبھار اس کے پردے میں سے ہولے ہولے بے حد آ ہستگی سے کوئی ایک پکھیرو ظاہر ہونے لگتا اور یکدم اسے سامنے پا کر ٹھٹک جاتا، اس کے پر ایک پل کے لیے ساکت ہو جاتے ، گرنے کو ہوتا تو اگلے پل پھر سے پھڑ پھڑانے لگتا اور اس کے سر پر سے سے گذر کر گاؤں کی جانب پرواز کر جاتا۔۔۔کبھی کوئی کونج بھی اس دھند میں سے ایسے نمودار ہوتی کہ وہ دھند میں دھندلی چٹی سفید نظر آتی۔۔۔ وہ بھی اسے دریا کے کنارے بیٹھا دیکھ کر ..دس برس کے امیر بخش کودیکھ کر۔۔۔جس کے برابر میں ایک چھوٹی چاٹی لسی سے لبریز دھری تھی جس پر دسترخوان میں پچھلی شب میں تندور میں لگائی گئی تین موٹی روٹیاں اور اچار کی چند پھانکیں بندھی تھیں۔۔۔۔اسے دیکھ کر دوسرے پرندوں کی مانند نہ ٹھٹھکتی نہ پل بھر کے لیے حیرت میں ساکت ہوتی۔۔۔جیسے دھند میں سے ظاہر ہونے سے سے پیشتر ہی اسے خبرتھی کہ جونہی وہ نمودار ہو گی اس کے سامنے امیر بخش بیٹھا ہوگا”-
اردو کے ساتھ پنجابی کی ملاوٹ پر اپنے ایک انٹرویو میں تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ، “سوائے قرۃ العین حیدر کے اردو زبان میں جتنی بڑی نثر لکھی گئی ہے، وہ سب پنجابیوں نے لکھی ہے- ایک ایسی زبان جس کا بڑا لٹریچر ان لوگوں نے لکھا ہے جن کی وہ زبان نہیں ہے۔ کرشن چندر، بیدی، منٹو، پطرس اور اس سے آگے ایک طویل فہرست ہے، کہاں تک نام گنوائے جاؤں؟ چونکہ خس و خاشاک کا پہلا حصہ مکمل طور پہ پنجاب کا احاطہ کرتا ہے لہذا اردو کے ساتھ پنجابی کی شمولیت واقعی ناگزیر دکھائی دیتی ہے-
لیو ٹالسٹائی نے کہا تھا کہ “عمدہ اور ردی فن کا واحد معیار شخصی لذت بن گیا ہے- خیر وہ ہے جو نفوس میں لذت بھڑکائے اور وہی جمیل بھی ہے”- یہی لذت اس ناول میں بھی نظر آتی ہے- گو کہ یہ “انداز منٹویت” نہیں ہے لیکن بہرحال شباہت اور امرت کور کو بیان کرتے ہوئے کسی حد تک یہ واضح ہے- اس کے علاوہ ہم جنس پرستی کے باب میں بھی مبہم اور سطحی سا انداز اپنا کر تارڑ صاحب نے روایتی بیانیے پر قناعت کی ہے- ہم جنس پرستی کے بارے نرم گوشہ اختیار کرتے ہوئے مصنف انعام اللہ کے جواب کے ذریعے لکھتا ہے کہ “ان جیسے لوگ ہماری روایت کا ایک حصہ ہیں۔۔۔اور یہ روایت مدتوں سے ہماری شاعری میں یہاں تک کہ تصوف میں بھی چلی آتی ہے۔۔۔اور کچھ لوگ اسے علت مشائخ کا نام بھی دیتے ہیں۔۔اور عطار کے اس لونڈے سے دوا لیتے ہیں ۔۔۔بے شک یہ ایک روحانی رشتہ تھا پر ہمارے شاہ حسین کے ہمراہ مادھو لال ہوا کرتا تھا اور مولانا روم شمس تبریز کے بغیر بے چین ہو جاتے تھے۔۔۔مزید وہ لکھتا ہے کہ “ہماری جنت میں۔۔۔ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہاں صرف حوریں نہیں،غلمان بھی ہوں گے۔۔ہم نے ہزاروں برس پیشتر پیدائشی مجبوری کی اس کج روی کو قبول کیا۔۔۔اپنی روائت میں شامل کر لیا”- اگر تارڑ صاحب ایسا غیر علمی اور سطحی انداز نہ اپناتے تو شاید ناول کا دوسرا حصہ مزید دلکش اور خوبصورت ہو جاتا- اسی طرح روایتی مذہب بیزاری اور ہیومنزم کا پرچار بھی اس ناول پر چھائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں-
مجموعی طور پر یہ ناول اردو ادب کا ایک بہترین ناول ہے- فینٹسی،شعور کی رو، کرداروں کا تاریخی واقعات سے تعلق ،کرداروں کے جبلی تضادات اس ناول میں واضح ہیں- اور ہاں،اس ناول میں بھی وہ چار مرغابیاں ہیں جن کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں ہے-